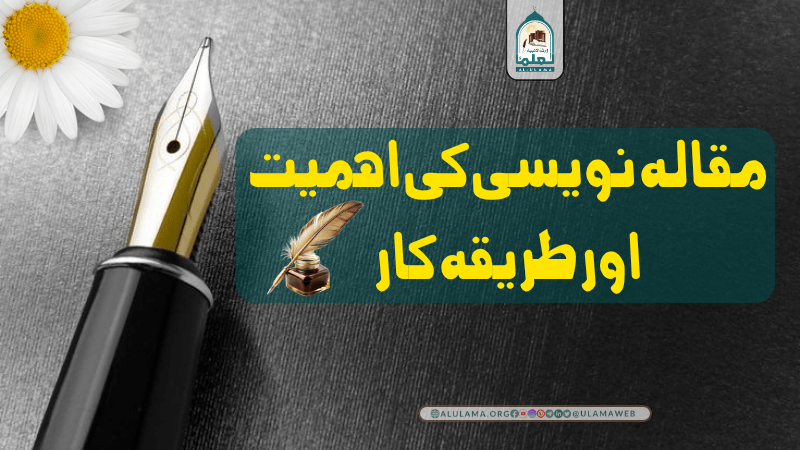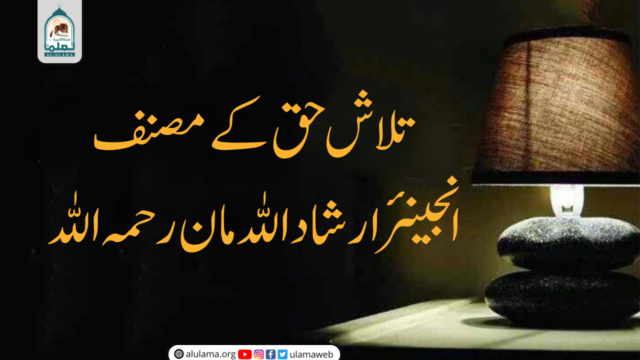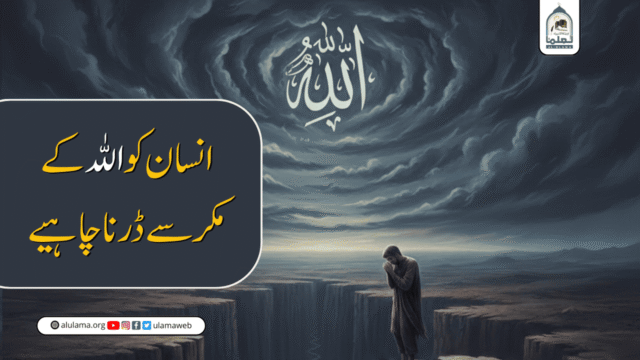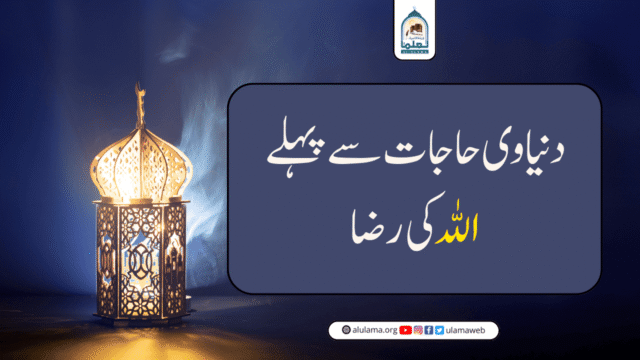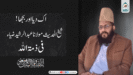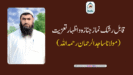مقالہ نویسی کی اہمیت اور طریقہ کار
مولانا محمد اسحاق بھٹی(رحمہ اللہ تعالی) لاہور
[مولانا محمد اسحاق بھٹی تمام جماعتی، دینی، علمی، ادبی اور صحافتی حلقوں میں محتاجِ تعارف نہیں ہیں۔ آپ صاحبِ قلم و قرطاس ہیں اور منفرد اسلوبِ تحریر رکھتے ہیں۔ گزشتہ ماہ جامعہ سلفیہ میں بطور مہمانِ خصوصی تشریف لائے۔ اس موقع پر آپ نے عالیہ اور عالمیہ کے طلبہ کو “مقالہ نویسی: ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار” پر لیکچر دیا۔ مفادِ عامہ کے پیشِ نظر معمولی ترمیم و اضافے کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔](ادارہ)
گرامی قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ؛ السلام علیکم!
مجھے آج اچانک مقالہ نویسی کی ضرورت، اہمیت اور طریقہ کار پر کچھ بیان کرنے کا حکم ملا ہے۔ سوچتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر کیا عرض کروں۔ میں مقرر نہیں ہوں، خطیب نہیں ہوں، واعظ نہیں ہوں۔ میرے اوصاف سے آپ سب واقف ہیں۔ اس کے باوجود مجھ غریب کو آپ کے حضور پیش کر دیا گیا ہے۔ اب میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ علماء کی مجلس میں بولنا بہت مشکل ہے اور خطیبوں کے سامنے زبان کھولنا بڑے جگر و دل کا کام ہے۔
لکھنا تنہائی کا کام ہے۔ آپ ایک کٹیا یا جھگی (جھونپڑی) میں بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی سنتا نہیں ہے۔ جس طرح مرضی لکھتے رہیے۔ الفاظ کو بڑھاتے رہیے، گھٹاتے رہیے۔ لیکن کسی مجلس میں اچانک بولنا، براہِ راست بات کرنا، خصوصاً علماء، خطیبوں، واعظوں اور مدرسین کے سامنے، یہ واقعی ایک بڑا امتحان ہے۔
گزارش ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ قلم کو سب سے اول ذکر کیا اور اس کو بڑا مقدس قرار دیا ہے، اس کی قسم کھائی ہے: و القلم وما يسطرون۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو پر تعلیم اور قلم کو اہمیت حاصل ہے اور اختلاف کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر زیادہ صحیح نہیں تو زیادہ غلط بھی نہیں کہ لکھنا، قلم کا استعمال کرنا، دماغ کا استعمال کرنا اور ذہن کو ایک طرف لگا دینا یہ قرآنِ حکیم کا حکم ہے۔ حدیث کا بھی یہی حکم ہے۔ آپ ﷺ کے وقت احادیث لکھی گئیں۔ جن کو آپ صحیفے کہتے ہیں۔ صحیفہ علی، صحیفہ عمر بن خطاب، صحیفہ عائشہ (رضی اللہ عنھم) جیسے مختلف صحائف ہیں۔ ان صحائف سے مراد وہ صحائف ہیں جن میں احادیث کو تحریری طور پر جمع کیا گیا۔ صحیفہ ہمام بن منبہ بھی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ وہ تمام حدیثیں انہوں نے جمع کیں جو مختلف کتب میں موجود ہیں۔ جسے ممتاز سکالر ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے چھاپ دیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے صحائف ہیں جو ابھی مخطوطوں کی شکل میں مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں۔
اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز لکھی جائے اور قلم کی زد میں آ جائے اور تحریر کی گرفت میں آ جائے وہ دیرپا ہوتی ہے۔ صدیوں پہلے لکھے گئے صحائف آج بھی موجود ہیں، اسی طرح قلم کا معاملہ ہے۔ سارے بزرگوں نے کتابیں لکھیں۔ دور نہیں جاتے۔ ہندوستان کو لیجیے، برصغیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، حجۃ اللہ البالغہ لکھی، اس میں تمام موضوعات آتے ہیں۔ یہ سب محفوظ ہے۔ اس پر مختلف کام ہوئے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے تفسیر لکھی، جو تفسیرِ عزیزی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اڑھائی پارے دستیاب ہیں۔ جبکہ باقی حصہ ۱۸۵۷ء کی جنگ میں ضائع ہو گیا، یا یہ لائبریری آف انڈیا، لندن میں پہنچ گئی۔ اسی طرح شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے اردو ترجمے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر موضح القرآن لکھی، اس کا تفصیلی تذکرہ میں نے خدام القرآن میں کر دیا ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ لکھنے کا طریقہ اور یہ انداز شروع ہی سے ہے۔ لکھنے ہی کی وجہ سے حدیثوں کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طرح راویوں کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں جو دوسری صدی ہجری سے لے کر نویں ہجری تک چلتا رہا ہے۔ اسماالرجال کا ہی مبارک سلسلہ ہے جس کی بدولت آج ہم حدیث کی صحت اور عدم صحت کو پہچان سکتے ہیں۔ حدیث ضعیف ہے تو راوی کا کیا حال ہے۔
یہاں میں تھوڑا اختلاف ذکر کرنا چاہوں گا، خصوصاً ضعیف حدیثیں یا موضوع… موضوع حدیثیں تو ٹھیک ہیں کہ ان کے بارے میں دوٹوک موقف اختیار کرنا چاہیے لیکن حدیث کو ضعیف قرار دینے میں ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے (معذرت کے ساتھ)۔ منکرینِ حدیث اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ مجھ سے ان کا رابطہ رہتا ہے، خصوصاً جب میں الاعتصام میں کام کرتا تھا، وہ اس وقت سے میرے رابطے میں ہیں۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ “تم بھی حدیث کے منکر، ہم بھی منکر”۔ میں نے کہا کہ “بندے میں کیسے منکر ہو گیا؟ ہم تو اہل حدیث ہیں”۔ کہنے لگے “تم اس طرح منکر ہو کہ یہ راوی تدلیس کرتا ہے، یہ موقوف روایت ہے، یہ مرسل ہے، یہ عزیز، یہ غریب ہے۔ تم ادھر سے ہاتھ لگاتے ہو، ہم سیدھا کہہ دیتے ہیں”۔ حدیث کی صحت اور عدمِ صحت بیان کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔
لکھنے کے کئی طریقے ہیں، ہمارا لکھنے کا بھی عجیب طریقہ ہے کہ ہم پڑھتے عربی میں ہیں، سوچتے پنجابی میں ہیں اور لکھتے اردو میں ہیں۔ عربی پڑھنی چاہیے، فارسی کی اہمیت ہے، سیکھنی چاہیے۔ اردو لکھنے کے لیے عربی اور فارسی کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بغیر اردو میں مہارت پیدا نہیں ہوتی۔ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی گرائمر تلفظ کی ادائیگی کو درست کر دیتی ہے۔ میں نے بہت سے ایسے لکھاری دیکھے ہیں جن کی کتب نہایت عمدہ ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو اقرار کو اِقرار، تعلق کو تعلق، تمدن کو تمدن کہتے ہیں۔
اردو کے مختلف موضوعات ہیں، مثلاً شخصیات، معاشیات، جغرافیہ، تاریخ وغیرہ۔ آپ نے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ ہر موضوع کی الگ الگ نفسیات ہیں اور مختلف زبانیں ہیں۔ افسانہ ہے تو اس کی اپنی زبان ہے، تاریخ کی اپنی زبان ہے، جغرافیہ کی اپنی زبان ہے۔ قرآنِ حکیم کی اپنی زبان ہے۔
ترجمہ کرنا ہے تو اس کا انداز الگ ہے، تفسیر لکھنی ہے تو اس کا اسلوب علیحدہ ہے۔ فقہ اور فتوے میں زبان اور طرح استعمال ہوتی ہے۔ حدیث کی تشریح میں زبان مختلف ہوگی، ناول کا اپنا انداز ہوگا۔
اگر آپ تاریخ پر لکھنا چاہتے ہیں، تو تاریخ کی نفسیات کو جانیے، تاریخ دانوں کو سمجھیں، تاریخی کتب کا بغور مطالعہ کریں۔ پھر آپ کو صحیح اندازہ ہو گا۔ سیرت پر لکھنا ہے تو اس کی زبان اور نفسیات کو سمجھیں، کتبِ سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کریں۔ اس کے لیے آپ کو تاریخ کی نسبت الگ الفاظ استعمال کرنے ہوں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں الگ انداز اور الفاظ، صحابہ کرام کے بارے میں الگ اسلوب اور الفاظ، عام لوگوں کے بارے میں الگ طریقہ کار، غیر مسلموں کے بارے میں الگ ترتیب اور الفاظ استعمال کرنے ہوں گے۔ اس پر بہت غور و فکر کرنا ہوگا تب جا کر آپ کوئی قابلِ قدر کام کر سکیں گے۔ آپ کے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اور ان کو مناسب جگہ پر ترتیب دینا ہو گا۔ شخصیت کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرنا ہو گا۔ ایک ہی جملے میں تمام مترادفات استعمال نہیں ہونے چاہئیں بلکہ ان الفاظ کو بچا کر رکھنا چاہیے اور مناسب موقع پر ہی ان کا استعمال صحیح ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے کے لیے اس زبان کا ماہر ہونا ازحد ضروری ہے۔
مولانا ظفر علی خان بہت اچھے مترجم تھے۔ سائنس کیا ہے؟ اس کا اتنا عمدہ ترجمہ کیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے کہ اگر وہ انگریز اس ترجمے کو دیکھ کر سمجھ سکتا تو وہ اپنی کتاب کو تلف کر دیتا۔ مولانا محمد حنیف ندوی مرحوم بھی بہت اعلیٰ پائے کے مترجم تھے، ان کے تراجم پڑھیں۔ انہوں نے امام غزالی کی کتابوں کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا ہے جو سرگزشتِ غزالی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
مولانا ابوالکلام آزاد نے قرآنِ حکیم کی تفسیر لکھی ہے۔ نہایت اچھی اور خوبصورت اسلوب ہے۔ مولانا عبدالسلام جو کہ بہت بڑے عالم تھے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ فرمانے لگے کہ “ابوالکلام، جبریل کی زبان بولتا ہے”۔ (اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو ابوالکلام کی زبان میں نازل ہوتا) اس لیے عرض ہے مولانا کی تفسیر ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ عربی الفاظ کو اردو کے قالب میں کیسے ڈھالا جاتا ہے۔ امام غزالی کی احیاء العلوم اور امام ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون کے ترجمے پڑھنے چاہئیں۔ مقدمہ ابن خلدون کے ایک حصے کا ترجمہ مولانا حنیف ندوی صاحب نے کیا ہے، ضرور پڑھیں، اس سے ترجمہ کرنے کا رجحان پیدا ہو گا۔
میں نے بھی ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے۔ محمد بن اسحاق مصنف کا نام ہے جو کہ ابن ندیم وراق بغدادی کے نام سے معروف ہے۔ اس کا مصنف شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی کتاب میں تمام مسالک کے علماء اور ان کی خدمات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ اس دور کے شعراء کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ طب اور ہندوستان میں طب کا آغاز کب ہوا، اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ ایک قسم کا انسائیکلوپیڈیا ہے۔ میں ترجمہ کر کے ادارہ ثقافتِ اسلامیہ میں مولانا محمد حنیف ندوی اور مولانا جعفر شاہ پھلواری کو دکھاتا تھا۔ جہاں کہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہوتی وہ کر دیتے تھے۔ ان کی رہنمائی میں یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ لوگوں نے اس کی تعریف کی کہ یہ بڑا سلیس ترجمہ ہے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہونے لگا تو ادارے کے ڈائریکٹر جناب سراج منیر صاحب (جو کہ بہت نفیس اور اچھے تھے، ابھی نوجوان تھے اور انہوں نے بڑا نستعلیق مزاج پایا تھا) تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ترجمہ ایسے شخص کو دکھانا چاہیے جو انگریزی اور فارسی جانتا ہو کیونکہ اسی کتاب کا فارسی اور انگریزی میں ترجمہ ہو چکا تھا۔ ہم نے بازار سے وہ کتابیں حاصل کر کے کسی انگریزی جاننے والے کو دیں تاکہ وہ ترجموں کا موازنہ کر سکے۔ اس نے رپورٹ میں لکھا کہ اردو کا ترجمہ فارسی اور انگریزی کی نسبت زیادہ اچھا ہے جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
اپنی اردو اچھی کرنے کے لیے ادب سے متعلق کتب پڑھنی چاہئیں۔ ویسے تو نصاب میں بھی عربی ادب کی کتب شامل ہوا کرتی تھیں۔ مثلاً سبع معلقہ، مقاماتِ حریری اور متنبی وغیرہ۔ امید ہے اب بھی نصاب کا حصہ ہوں گی۔ یہ اخلاقیات کی کتابیں نہیں بلکہ ان کا تعلق عربی ادب سے ہے۔
اگر آپ اردو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو جوش ملیح آبادی کی کتاب یادوں کی برات پڑھیے۔ یہ کتاب جھوٹ کا پلندہ ہے لیکن اردو ادب کا مرقع ہے۔ وہ الفاظ کا بادشاہ ہے، الفاظ کا بے پناہ ذخیرہ ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی کی کتابیں پڑھو، بعض کتب نایاب ہیں، لیکن علامہ سید سلمان ندوی، قاضی سلیمان منصور پوری، ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں میسر ہیں، یہ ضرور پڑھنی چاہئیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر، یہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ ان کی کتابیں پڑھیں، بہت مفید ہیں۔ مولانا غلام رسول مہر اور مولانا ابوالکلام آزاد کی کتابیں پڑھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، خصوصاً غلام رسول مہر کی کتب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیات پر کیسے لکھا جاتا ہے، تاریخ کیا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے۔
مولانا غلام رسول بہت اچھے اور ماہر تاریخ دان تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں الفہرست کا ترجمہ کر رہا ہوں تو انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اب جغرافیہ تبدیل ہوا ہے، نئے مقامات ہیں، لہٰذا آپ مجھ سے رہنمائی لے لیا کریں۔ مگر افسوس کہ میں ان سے صحیح استفادہ نہ کر سکا۔ مہر صاحب نے شہدائے بالاکوٹ پر لکھا اور خوب لکھا ہے۔
لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تعصب سے بالاتر ہو۔ میں نے اپنی تحریروں میں سب پر لکھا اور خوب لکھا۔ حتیٰ کہ گیانی ذیل سنگھ پر بھی لکھا۔ میری کتابیں پڑھ کر راولپنڈی سے ایک صاحب نے رابطہ کیا اور کہا کہ “اہلِ حدیث ہو کر آپ نے بڑی فراخدلی سے سب پر لکھا ہے اور تعصب سے کام نہیں لیا”۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مولانا ابوالحسن ندوی پر لکھیں، آپ مولانا عبدالقادر رائے پوری پر لکھیں۔ میں نے کہا “میں ان پر ضرور لکھوں گا، ان شاء اللہ”۔
میں نے فقہائے ہند میں سب پر لکھا جبکہ ہمارے دوست اپنی کتابوں میں اہل حدیث علماء اور فقہاء کا تذکرہ نہیں کرتے۔
ماضی قریب کے علماء میں مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا عبدالسلام کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں، نیز دارالمصنفین کی سیرت صحابہ کرام اور دیگر کتب پڑھیں، بہت مفید ہیں، لکھنے کا اسلوب معلوم ہوتا ہے۔
مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہے کہ جامعہ سلفیہ نے اپنے آخری سال کے طلبہ کے لیے علمی مقالہ لکھنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ یہ ایک اچھی اور عمدہ کوشش ہے، اس سے طلبہ کے اندر لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گی۔ اس سے قبل میں نے کسی اور ادارے کے بارے میں نہیں سنا کہ وہاں مقالہ نویسی کا کام ہوتا ہو۔
میں اپنے عزیزوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ لکھنے سے پہلے اس موضوع پر خوب مطالعہ کریں۔ الفاظ کا ذخیرہ جمع کریں۔ اگر دس عالموں کے بارے میں لکھنا ہو تو الفاظ بدلنے ہیں۔ آپ کیسے بدلیں گے؟ یہ بھی عالم ہیں، وہ بھی عالم ہیں۔ یہ مدرس ہیں، وہ بھی مدرس ہیں۔ یہ خطیب ہیں، وہ بھی خطیب ہیں۔ یہ مقرر ہیں، وہ بھی مقرر ہیں۔ یہ سیاست دان ہیں، وہ بھی سیاست دان ہیں۔ ایک کے بارے میں استعمال ہونے والے الفاظ دوسرے کے بارے میں استعمال نہ کریں۔ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس الفاظ کا وافر ذخیرہ ہو اور ہر ایک کو اس کی شخصیت کے مطابق حصہ دے سکیں۔
ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ آپ مترادفات استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ دس یا پانچ الفاظ جو ایک معنی لیتے ہیں، وہاں ایک لفظ استعمال کریں۔ نو کو بچا کر رکھیں، وہ دوسری جگہ استعمال کریں۔ اکثر طلبہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ “جناب، لکھنے کا طریقہ سکھائیں؟” لکھنے کا طریقہ مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ مشکل اس وقت ہے کہ جس موضوع پر لکھنا ہے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ مثلاً تفسیر جلالین پر لکھنا ہے تو کم از کم یہ تو معلوم ہو کہ دو جلال کون تھے۔ اور تفسیر پر لکھتا ہے تو اردو تفسیروں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس جس موضوع پر بھی لکھنا چاہتے ہیں اس کا وسیع مطالعہ کریں، پھر قلم پکڑیں۔
میرے عزیزو! اگر آپ نے اردو میں لکھنا ہے تو اردو کی کتب پڑھیں، اگر عربی میں لکھنا ہے تو عربی کی کتب کا مطالعہ کریں، پھر بات بنے گی۔ خصوصاً جدید کتب کو زیرِ مطالعہ رکھیں۔ اور اس بات کا پورا خیال کریں کہ مقالے میں جو بات لکھنی ہے اس کا پورا حوالہ دیں۔ آپ جتنے حوالے دیں گے اتنا ہی آپ کا مقالہ پختہ اور علمی ہوتا جائے گا۔ اگر آپ حوالہ نہیں دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ چور مصنف ہیں، اس لیے سرقے سے بچنے کے لیے حوالہ ضروری ہے۔ اگر آپ حوالہ نہیں دیتے اور کسی کتاب سے کوئی بات نقل کر دیتے ہیں تو یہ علمی سرقہ ہو گا، جو بہرحال ایک کوتاہی ہے۔
آخری بات یہ عرض کروں گا کہ آپ کو باعمل لکھاری ہونا چاہیے، اچھی صحبت اختیار کریں۔ اچھے لوگوں میں بیٹھیں، عملی زندگی نظر آنی چاہیے۔ اور اپنی تحریروں میں بھی صاف ستھری زبان استعمال کریں تاکہ لوگ پڑھ کر آپ کے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ عرب کے لوگ آپ ﷺ کی زبان سن کر ہی کہہ دیتے تھے کہ یہ ان پڑھ کی زبان نہیں ہے۔ اس قدر عمدہ اور شائستہ گفتگو ہوتی کہ لوگ بہت متاثر ہوتے تھے، یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ زبان جتنی صاف ہو گی، اتنا ہی زبان کا اثر ہو گا۔
میں آخر میں جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کا موقع دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین
(اپریل 2009ء ترجمان الحدیث فیصل آباد ص 22 تا 29)
انتخاب و ٹائپینگ: محمد مرتضی ساجد