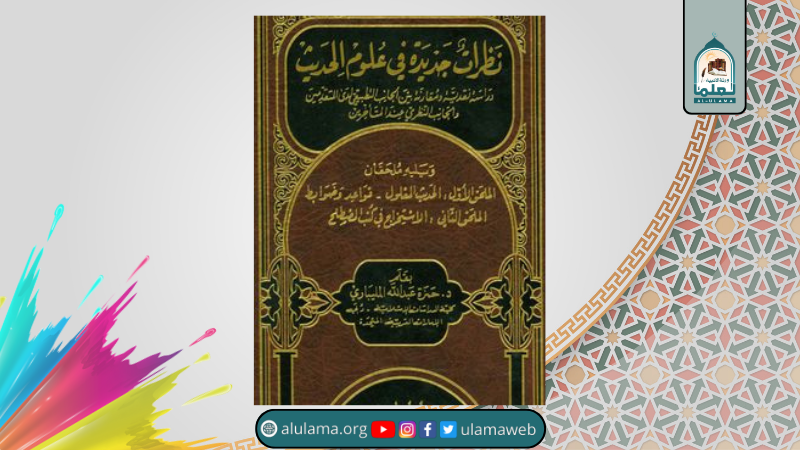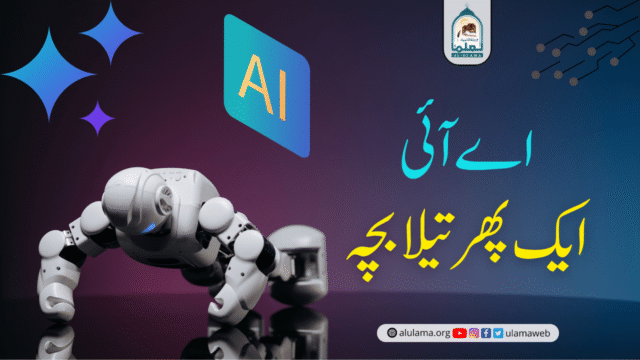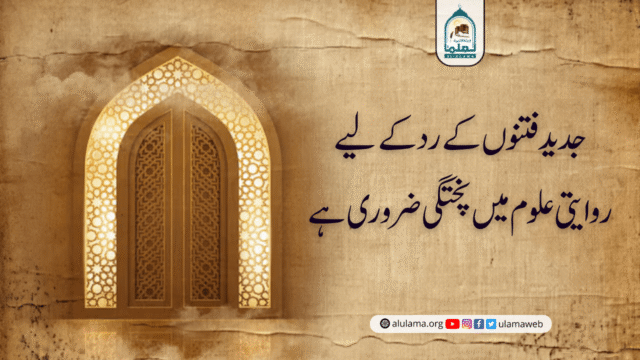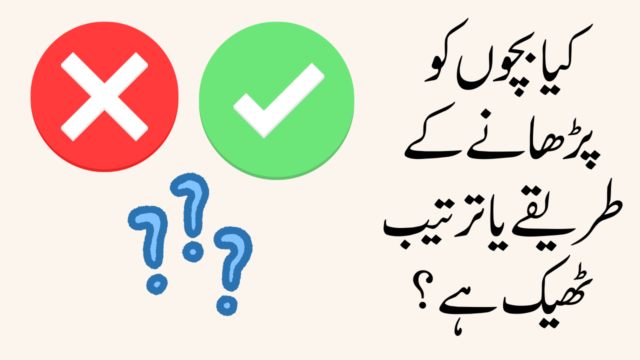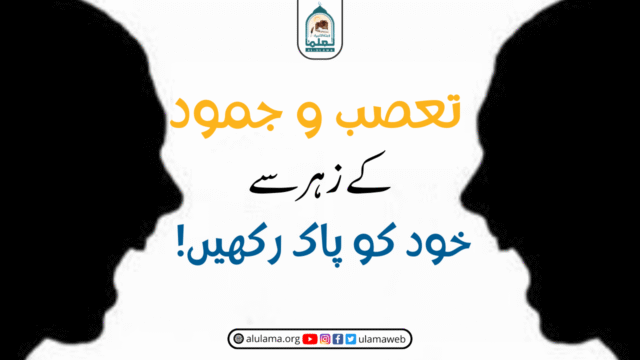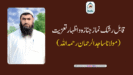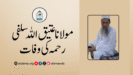نظرات جدیدۃ فی علوم الحدیث
اس کتاب کا بھی دوسرا ایڈیشن ہی پیش نظر ہے ، مکمل نام اس طرح ہے : ’نظرات جديدة في علوم الحديث ، دراسۃ نقدیۃ و مقارنۃ بین الجانب التطبیقی لدى المتقدمين و الجانب النظري عند المتأخرين‘ ۔
اس کتاب میں ’ علوم الحدیث ‘ کو مصنف نے جن ’ نئی نظروں ‘ سے دیکھا ، اس کا کسی حد تک اندازہ سابقہ کتاب کے تعارف سے ہوجاتا ہے، لہذا یہاں کوشش کرتا ہوں، وہی ذکر کروں جو پہلی کتاب میں رہ گیا ہے۔
وجہ تالیف:
مصنف کا کہنا ہے ، ہمارے زمانے میں ’ علوم حدیث ‘ سطحیت کا شکار ہیں ، بہت سارے لوگ چند محدثین ، فقہاء اور اصولیوں کے نتیجہ فکر کو پڑھنا پڑھانا اصول حدیث کا علم سمجھ لیتے ہیں ، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں میں اس علم کے متعلق وہ غلط تصور پیدا ہوچکا ہے ، جو ناقدین حدیث کے عملی اور تطبیقی کام سے میل نہیں کھاتا ، لہذا ضرورت ہے کہ ’ علوم حدیث ‘ پر نظرثانی کی جائے ، اور انہیں اس انداز سے مرتب کیا جائے کہ نظریاتی تاصیلات اور متقدمین کی عملی تطبیقات میں موافقت پیدا ہو ۔
مضامین کتاب دو حصوں میں منقسم ہیں ، پہلی قسم ’ الحقائق العلمیۃ ‘ ہے ، جبکہ دوسری قسم کو ’ محتوی علوم الحدیث عند المتقدمین ‘ کاعنوان دیا گیا ہے ۔
پہلی قسم کے ابتدائی عناوین میں یہ کوشش کی ہے کہ متقدمین و متاخرین میں فرق واضح کرسکیں ، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ متقدمین سے مراد ’ عصر الروایۃ ‘ کے حفاظ ہیں ، جبکہ متاخرین سے مراد بعد کے مرحلے کے لوگ ہیں ۔ یہ بھی وضاحت کی ہے کہ خیر القرون ، یا تیسری صدی کو حد فاصل قرار دینا درست نہیں ، یہ بھی فرمایا کہ پانچویں اور چھٹی صدی ہجری انتقالِ منہج اور تبدیلی کا زمانہ ہے ۔گویا ’ خالص متقدمین ‘ کا زمانہ چوتھی صدی تک ختم ہوجاتا ہے ، جبکہ ’ محض متاخرین ‘ کا زمانہ ساتویں صدی سے شروع ہوتا ہے ۔
علوم حدیث میں تصنیف کا طریقہ:
فرماتے ہیں ، عصر روایت میں تصنیف کی گئی کتابیں مثلا امام مسلم کی تمییز ، معرفۃ علوم الحدیث للحاکم ، اور خطیب کی الکفایۃ ! کا منہج درست ہے کہ اس میں قواعد ،احکام و مسائل کو عصر روایت کے مطابق ذکر کیا گیا ہے ، لیکن ابن الصلاح نے آکر ایک جدید اسلوب اپنایا ہے ، جس میں اصطلاحات اور تعریفات میں منطقی مجبوریوں سے متاثر ہوئے ہیں ، گو اس کا مقصد طلاب کے لیے تیسیر اور آسانی تھی ، لیکن اس انداز کی وجہ سے فہمِ قواعد اور تحریرِ مسائل میں کئی ایک کج فہمیاں پیدا ہوئیں اور غلط نتائج برآمد ہوئےہیں ۔
مؤلف کا موقف ہے کہ اس فن کا ’ مصطلح الحدیث‘ کے عنوان سے رائج ہونا بھی اسی سطحی اور منطقی اصطلاح بندی کا نتیجہ ہے ، ورنہ اس سے پہلے یہ ’ علوم الحدیث ‘ وغیرہ ناموں سے معروف تھا۔
چند اصطلاحات کا جائزہ:
مصنف کے نزدیک جو اصطلاحات متاخرین کے طریقہ تصنیف کے باعث متاثر ہوئی ہیں ، ان میں بطور مثال ’ صحیح ، حسن ، منکر ، شاذ ، علت ، زیادۃ الثقۃ ، تفرد ، مخالفت ، الاعتبار‘ وغیرہ ذکر کی جاسکتی ہیں ۔
پھر تفصیلی گفتگو کے لیے تین اصطلاحات کو اختیار کیا ہے ۔
حسن : اس میں ترمذی ، خطابی ، ابن الجوزی ، ابن الصلاح وغیرہ علما کی تعاریف ذکر کی ہیں ، اور استدراک میں متقدمین کی بجائے ، ابن حجر اور عراقی وغیرہ متاخرین کے اقوال پیش کیے ہیں! ۔ موصوف کا موقف ہے کہ ’ حسن ‘ کی کوئی لگی بندھی تعریف نہیں ، امام ترمذی نے بھی جو تعریف کی ہے ، ایک تو وہ ان کی کتاب کے ساتھ خاص ہے ، دوسرا اس کا معنی وہ نہیں ، جو حد بندیاں متاخرین نے لگائی ہیں ، اور پھر بعد میں ’ حسن صحیح ‘ کے درمیان تطبیق دینے میں الجھتے رہے ہیں ، کیونکہ تعریف سے دونوں کو الگ کرچکے تھے۔ حالانکہ متقدمین کے ہاں صحیح اور حسن دونوں میں ایسا کوئی فرق ہے ہی نہیں ۔ بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں ، متقدمین ’ صحیح ‘ کا اطلاق بھی صرف ثقہ کی روایت پر نہیں کرتے تھے ۔
منکر و شاذ : منکر کے متعلق فرماتے ہیں متاخرین کے ہاں اس کی تعریف ہے ’ مارواہ الضعیف مخالفا للثقۃ ‘ ، حالانکہ متقدمین کے ہاں منکر ہر وہ حدیث ہے ، جس کا مصدر غیر معروف ہو ، چاہے راوی ثقہ ہو یا ضعیف ، مخالفت ہو کہ نہ ہو ۔
شاذ متاخرین کے ہاں ’ مارواہ الثقۃ مخالفا لمن ہو أوثق ‘ ہے ، جبکہ متقدمین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے ، لیکن اکثر متقدمین کی رائے میں اس سے مراد راوی کاتفرد ہے ، چاہے ثقہ ہو یا ضعیف ۔
متقدمین کے ہاں علوم حدیث:
اس حصے کی ابتدا اس بات سے کی گئی ہے ، کہ متقدمین نرے محدث نہیں تھے ، بلکہ حدیث کی فقہی مباحث میں بھی مہارت رکھتے تھے ، مسستشرقین اور ان پر ایمان لانے والوں کا محدثین کو یہ الزام دینا کہ انہوں نے صرف اسانید کو دیکھا ہے ، تحقیق متون پر توجہ نہیں دی ، یہ سوائے الزام کچھ نہیں ، محدثین کا اپنی کتب کو فقہی ابواب پر مرتب کرنا ، احادیث پر دقیق عناوین قائم کرنا اور نقد روایت میں ان کے اقوال اس بات کا بین ثبوت ہیں ۔ علی بن مدینی ، یحی بن معین ، امام احمد اور دیگر کئی ایک ناقدین سے انہوں نے کئی ایک اقوال اور مثالیں ذکر کی ہیں ، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین محدثین نے روایات کے تحقیقی و فقہی دونوں پہلؤوں پر خصوصی توجہ دی ہے ،۔البتہ متاخرین کے ہاں یہ معاملہ ذرا مختلف ہے ، عصر روایت کے بعد نہ صرف یہ کہ محدثین میں ’ تفقہ ‘ مفقود ہونے لگا ، بلکہ ان کے ہاں ’ نقد روایت ‘ کا منہج بھی تبدیل ہوگیا۔یوں بعد میں مستشرقین کو احادیث پر تابڑ توڑ حملے کرنے کا موقعہ ملا ، اور ان سے متاثرین نے تحقیقِ حدیث کے لیے اپنے تئیں قرآن ، عقل ، اورتاریخی واقعات کا نام لینا شروع کیا۔
محدثین پر احادیث گھڑنے کے الزام کی تردید کے تسلسل میں ہی انہوں نے ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے ، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ محدثین جھوٹی احادیث رائج کرنے والے نہیں ، بلکہ ان کا پردہ چاک کرنے والے ہیں ، موضوع اور من گھڑت احادیث ، اور ایسی روایتیں گھڑنے والے اور انہیں بیان کرنے والے لوگوں کے خلاف محدثین و ناقدین کی خدمات روز روشن کی طرح واضح ہیں ، جن کا انکار کوئی اندھا ہی کرسکتا ہے ۔ یہاں ایک بہت خوبصورت نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ’ داخلی و خارجی نقد ‘ کا جو اسلوب محدثین کا ہے ، عین درست ہے ، جبکہ جو فضول تصور مستشرقین وغیرہ کا ہے ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے ،جن کے پاس ’ اسانید‘ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ، اور انہوں نے مجبور ہو کر ٹامک ٹوئیوں کی کوئی حد مقرر کرنے کے لیے صحرا میں لکیریں کھینچنے کی کوشش کی ہے ۔
متقدمین کا منہجِ تصحیح و تعلیل:
اس عنوان کےتحت مصنف نے اس منہج کو واضح کرنےکی کوشش کی ہے ، جس پر متقدمین عمل پیرا تھے۔ لیکن چونکہ انہیں اصطلاح بندی اور تاصیل سے چڑ ہے ، اس لیے کوئی مفہوم و متعین بات نہیں کرسکے۔ کوشش کرکے اس بحث کے اہم نکات ذکر کرتا ہوں :
1۔ متقدمین ہر اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں ، جس کے راویوں کے صدق اور سند کے متصل ہونے کی شکل میں درست ہونے کا انہیں یقین ہوجائے ، چاہے وہ راوی عمومی درجے کے اعتبار سے ثقہ ہو یا ضعیف ۔
2۔ اور ہر وہ حدیث جس میں کسی راوی کی غلطی یا وہم کا انہیں قوی احساس ہو ، اس کی روایت کو رد کردیتے ہیں ، راوی عمومی درجے میں چاہے ثقہ ہو یا ضعیف ۔
3۔ راوی کے صدق ، ضبط اور اتقان کا فیصلہ بھی وہ اس کی روایات کی روشنی میں کرتے ہیں ، اگر اس کی عموما روایات دوسرے رواۃ کے مطابق ہوئیں تو یہ اس کے ثقہ ہونے کی دلیل ہے ، اور جس کی روایات میں دوسروں سے بہ کثرت اختلاف ہو ،تو اس کی غلطیوں اور اوہام کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ، اس کا مرتبہ طے کیا جاتا ہے ۔
4۔ سابقہ نکتے سے واضح ہوتا ہے کہ متقدمین کے ہاں تحقیقِ روایت کی ابتدا متاخرین کی طرح راوی کے بارے میں کہے گئے کلمات ’ ثقہ ، ضعیف ، متروک ‘ وغیرہ سے نہیں ہوتی تھی ، بلکہ راویوں کے یہ مراتب ان کی مرویات دیکھنے کے بعد طے ہوتے تھے۔
5۔ روایات کا مقارنہ کرتے ہوئے ناقدین ، قرآن ، سنت ، عملی واقع ، عرف ، زمان و مکان ، حالات و واقعات کو بھی دیکھتے تھے ، لہذا جس روایت میں بظاہر ان چیزوں سے تعارض پایا جاتا تھا ، اس کی خوب خوب تحقیق کی جاتی تھی ۔ ا س عرق ریزی کے باعث ناقدین میں یہ ملکہ اور مہارت پیدا ہوگئی تھی کہ ثقات کی روایات میں غلطیاں فورا پہچان لیتے تھے ، اور ضعفا کی روایتوں میں درست باتیں نکھرکر ان کے سامنے آجاتی تھیں ۔
مصنف نے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ اس کتاب کی اصل ان کا ایک مقالہ ہے ، جو انہوں نے صحیح بخاری میں منہجِ نقد کے بیان کی وضاحت کے لیے کسی کانفرنس میں پڑھا تھا ، بعد میں کچھ حک و اضافہ کرکے اسے ایک مستقل کتاب کی شکل دے دی ۔ لیکن ابھی بھی محسوس ہوتاہے کہ بعض مباحث میں صحیح بخاری و صحیح مسلم اور مستشرقین کا ذکر بے ربط آجاتا ہے ، اور بعض جگہ میں باوجود تفصیلی بحث کی ضرورت کے صرف امام بخاری کے ذکر یا عقل پرستوں کے متعلقہ اعتراضات کے رد پر اکتفا کرلیا گیا ہے۔